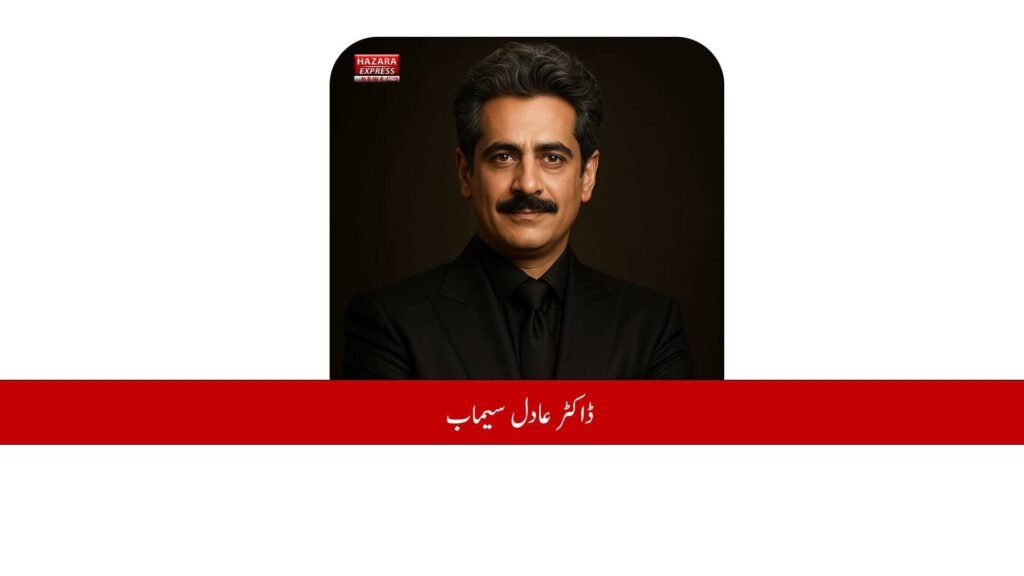تحریر: ڈاکٹر عادل سیماب
مولانا عبید اللہ سندھی برصغیر کی تاریخ میں ایک غیر معمولی شخصیت ہیں۔ وہ ایک طرف عالمِ دین تھے، دوسری طرف سیاسی انقلابی بھی۔ اُن کی فکری دنیا میں اسلام، شاہ ولی اللہ کی اصلاحی روایت، اور اشتراکیت کے اثرات سبھی جمع نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اُنہیں مارکسسٹ زاویے سے دیکھیں تو کئی بنیادی تضادات سامنے آتے ہیں۔
۱۔ طبقاتی جدوجہد بمقابلہ مذہبی ہم آہنگی
مارکسزم کی بنیاد طبقاتی جدوجہد پر ہے: بورژوازی (سرمایہ دار طبقہ) اور پرولتاریہ (مزدور طبقہ) کے بیچ تضاد۔ مولانا سندھی نے بھی استحصالی طبقات — جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور سامراجی قوتوں — پر تنقید کی، لیکن اُنہوں نے یہ تجزیہ خالص طبقاتی بنیاد پر نہیں کیا۔ ان کا نقطۂ آغاز اسلام تھا، جہاں مساوات اور عدل کو مذہبی فریضہ سمجھا گیا۔
مارکسی نگاہ سے یہ کمزوری ہے، کیونکہ طبقاتی جدوجہد کو “اخلاقی یا مذہبی وعظ” کے ساتھ ملا دینے سے استحصال کے ڈھانچے کو سائنسی طور پر سمجھنے کی صلاحیت دھندلا جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سندھی کا تجزیہ کبھی “طبقاتی شعور” کی صورت اختیار نہ کر سکا، بلکہ ایک “اخلاقی اصلاح” کے بیانیے تک محدود رہا۔
۲۔ مذہب کا کردار
مارکس کے نزدیک مذہب “لوگوں کی افیون” ہے — یعنی مظلوم طبقوں کو مصنوعی تسلی دینے والا آلہ۔ مولانا سندھی نے بالکل اس کے برعکس مذہب کو حل کے طور پر پیش کیا۔ اُنہوں نے اسلام کو ایک ایسا ہمہ گیر نظام قرار دیا جو معاشی انصاف بھی دے سکتا ہے اور روحانی سکون بھی۔ مارکسی نقطۂ نظر سے یہ ایک بڑا تضاد ہے، کیونکہ مذہب کو بنیاد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ طبقاتی تضاد کا سائنسی تجزیہ “ماورائی اصولوں” کے تابع کر دیا جائے۔ یوں مذہب، جو اصل میں طبقاتی استحصال کو جواز دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے، انقلابی تبدیلی کے آلے کے طور پر محدود ہو جاتا ہے۔
۳۔ سوشلزم کا جزوی اثر
مولانا سندھی نے روس میں قیام کے دوران کمیونزم اور سوشلزم سے گہرا اثر قبول کیا۔ اُنہوں نے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، مزدور و کسان کے حقوق، اور جاگیرداری کے خلاف موقف اختیار کیا۔ یہ سب مارکسزم کے ساتھ قریب تر لگتا ہے۔ لیکن اُنہوں نے کمیونزم کو مکمل طور پر قبول نہیں کیا۔ اُن کے نزدیک یہ ایک “ردعمل” تھا ظلم کے خلاف، اور اسلام اس سے بہتر اور ہمہ گیر نظام رکھتا ہے۔ مارکسی نگاہ میں یہ موقف “ایکلیکٹسزم” (مختلف خیالات کو ملانے) کی مثال ہے جو کسی ایک واضح، سائنسی انقلابی راستے کو اپنانے کے بجائے اصلاحی اور نیم انقلابی راہ دکھاتا ہے۔
۴۔ عملی سیاست کی حدود
مولانا سندھی کے سیاسی منصوبے — جیسے اُن کا “مہابھارت سوراجیہ پارٹی” کا منشور — طبقاتی بنیاد پر کوئی مضبوط تنظیم نہیں بنا سکے۔ وہ عوامی تحریک پیدا نہ کر سکے جو سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ ڈھانچے کو جڑ سے ہلا دیتی۔ یہ کمی بھی مارکسی نقطۂ نظر سے واضح ہے، کیونکہ حقیقی تبدیلی کے لیے محض خیالات کافی نہیں، بلکہ ایک منظم پرولتاری قیادت اور طبقاتی جدوجہد درکار ہے۔ سندھی کی تحریک زیادہ تر فکری اور انفرادی سطح پر رہی، جس سے وہ “یوٹوپیائی” (خیالی) اصلاح پسند کے قریب دکھائی دیتے ہیں۔
۵۔ تاریخی اہمیت
مارکسسٹ نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو عبید اللہ سندھی کو “پروگریسو اصلاح پسند” یا “اسلامی سوشلسٹ مفکر” کہا جا سکتا ہے، مگر انہیں مکمل انقلابی یا مارکسی مفکر نہیں کہا جا سکتا۔ وہ سرمایہ دارانہ اور سامراجی استحصال کے خلاف ضرور کھڑے ہوئے، لیکن اُن کا حل ایک ایسا امتزاج تھا جو طبقاتی سیاست کو مذہبی اخلاقیات میں جذب کر دیتا ہے۔ یہ امتزاج ایک “نیم شعور” پیدا کرتا ہے جو نہ خالص طبقاتی جدوجہد تک پہنچتا ہے اور نہ مذہبی روحانیت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے۔