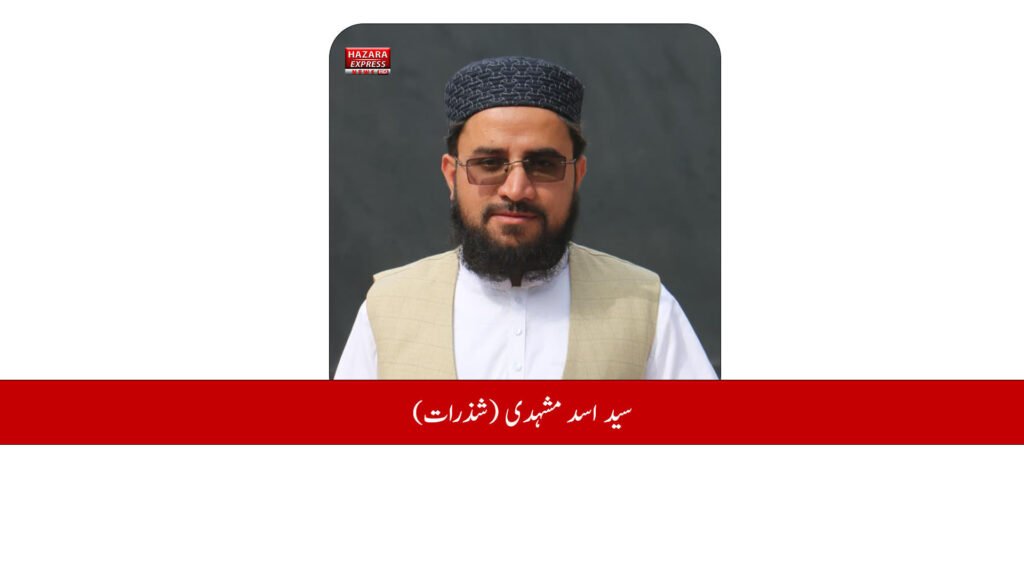تحریر: سید اسد مشہدی
پہلا شذرہ:
روایت و جدیدیت کی کشمکش ہمارے فکری افق پر ایک مستقل اور گہرا موضوع ہے۔ میرے فہم کے مطابق روایت، دراصل ایک ایسے ادراکِ مسلسل و متواتر کا نام ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا آیا ہے۔ یہ ایک ایسا علمی و فکری سرمایہ ہے جس میں زندگی کے ساتھ جڑت اور تجربے کی گہرائی شامل ہے۔ البتہ اس روایت کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں تجدید و تطویر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہوں۔ نہیں! اس کے برعکس روایت اپنی اصل میں وسعت اور نمو کی استعداد رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی قریب کی علمی روایت نے، اپنی داخلی پیچیدگیوں اور ممکنہ کمزوریوں کے باوجود، اس تسلسل کو قائم رکھنے کی سعی بھی کی اور اپنی بساط کے مطابق اس کے تقاضے نبھانے کی کوشش بھی کی۔
اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مذہبی علما نے مغربی فکر کو سمجھے بغیر اسلام کاری کا عمل شروع کیا۔ یہ تعریض میرے نزدیک محلِ نظر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اہلِ علم کے ادراکِ مغرب میں کسی نہ کسی درجے کا التباس یا خطا واقع ہوئی ہوگی، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ اسلامائزیشن کے عمل کی بنیاد ہی غیر علمی یا غیر اسلامی تھی۔ دینی فقہ و اصول کے دائرے میں رہتے ہوئے اس عمل کی کلی نفی ممکن نہیں، اور نہ ہی اسے شرعی یا اسلامی روایت سے بالکل باہر قرار دیا جا سکتا ہے۔
اسی بحث کے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ میں روایت پرستی کے جامد اور متحجر رویے کا قائل نہیں، جو ہر تبدیلی کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کے برعکس میں روایت پسندی کے رویے کو زیادہ درست سمجھتا ہوں۔ روایت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ روایت کو مانا جائے، مگر اس میں وسعت اور انفتاح کے امکانات کو بھی زندہ رکھا جائے۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو معاصر دنیا میں ابھرنے والے رجحانات مثلاً فقہِ تیسیر میرے نزدیک نہ صرف قابلِ فہم ہیں بلکہ اپنی جگہ درست بھی ہیں، کیونکہ یہ روایت کو ایک نئے تناظر میں برتنے کی کوشش ہیں۔
یوں یہ واضح ہوتا ہے کہ روایت اور جدیدیت کو محض متصادم دھڑوں کے طور پر دیکھنا درست نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم روایت کو کس زاویے سے لیتے ہیں: جامد و منجمد پیرائے میں یا متحرک و وسیع تناظر میں۔
دوسرا شذرہ:
میرے نزدیک یہ موقف زیادہ محلِ اعتبار نہیں کہ روایت کی مطلق کفایت پر اصرار کیا جائے۔ گویا یہ دعویٰ قائم کیا جائے کہ آج کے تمام مسائل اور زمانے کے ہر معضل کا حل فقط اور فقط ماضی کی علمی تراث میں ہی پوشیدہ ہے۔ اگر بفرضِ محال ایسا ہو تو یہ بلاشبہ ہمارے لیے کمال اور نعمتِ عظمیٰ سے کم نہ ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری تاریخ کا سرمایۂ علم ہر دور کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہونا لازم و لابدی نہیں۔ زمانہ بدلتا ہے، انسانی ضروریات میں وسعت اور تنوع پیدا ہوتا ہے، اور نئے سوالات نئے زاویوں سے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے یہ خیال کہ محض ماضی کی کتابوں اور روایت کے صفحات ہی میں ہر سوال کا جواب مل جائے گا، اپنے اندر جمود اور سختی کا پہلو رکھتا ہے۔
اس کے برخلاف میرا رجحان یہ ہے کہ جہاں تجدید کی ضرورت محسوس ہو، وہاں جمود پر اصرار کو ترک کر کے تجدید و تطویر کی سمت میں پیش قدمی کی جائے۔ یہی رویہ زیادہ صائب اور دانشمندانہ معلوم ہوتا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ایک اہم تنبیہ بھی ضروری ہے:
یہ تجدید کسی صورت مغرب کی اندھی تقلید پر مبنی نہ ہو۔ مغربی فکر کے سانچوں میں ڈھل جانا اور ان کے فکری و تہذیبی سانچوں کو بلا تنقید اپنانا نہ صرف غیر ضروری بلکہ ہماری اپنی فکری خودی کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔
اصل ضرورت اس امر کی ہے کہ تجدید کا عمل ہمارے اپنے اصولی اور فقہی مناہج کے مطابق انجام پائے۔ یہ تجدید اس نیت سے ہو کہ ہمارے معاشرے کی حقیقی اور داخلی ضروریات پوری ہوں، نہ کہ یہ عمل دوسروں کی خوشنودی یا خارجی دباؤ کے تحت برتا جائے۔ تجدید کا اصل مقصد روایت کی روح کو باقی رکھتے ہوئے اس میں زندگی اور نمو کے نئے امکانات پیدا کرنا ہے، تاکہ روایت جمود کا شکار نہ ہو بلکہ نئے زمانے کی روشنی میں اپنی معنویت برقرار رکھ سکے۔
یوں دیکھا جائے تو روایت اور تجدید ایک دوسرے کی ضد نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے عوامل ہیں۔ روایت ہمیں جڑوں سے جوڑتی ہے اور تجدید ہمیں نئی فضاؤں میں سانس لینے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ حقیقی کامیابی اسی وقت ہے جب دونوں کو باہم مربوط کر کے آگے بڑھا جائے۔
تیسرا شذرہ:
اس باب میں میرے نزدیک سب سے نمایاں و معتبر سرمایہ وہ علمی و روحانی وراثت ہے جو حضرتِ امامِ ربانی، امامِ عالی مقام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے علوم و معارف کی صورت میں ہمیں میسر ہے۔ ان کے افکار و نظریات اور ان کے جلیل القدر شارحین، بشمول امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھیؒ کی تحقیقات و مباحث، میرے لیے محض ایک علمی ذخیرہ نہیں بلکہ ایک زندہ اور فعال میراث ہیں جو فکر و عمل کے توازن میں اپنی مثال آپ ہیں۔ میں انہیں اپنی فکری و روحانی شناخت کا جوہرِ اصیل اور اپنی علمی نسبت کا حقیقی سرمایہ تصور کرتا ہوں۔
عہدِ حاضر کے تناظر میں دیکھا جائے تو شاہ صاحب کی یہ مساعی صرف ہمارے اپنے معاشروں ہی میں نہیں، بلکہ مغربی دنیا کے فکری و تہذیبی ماحول میں بھی بڑی معنویت رکھتی ہیں۔ آج مغرب اپنی مابعدالطبیعیاتی بے سمتی اور فکری خلجان کے باعث جس اضطراب کا شکار ہے، وہاں کی اعلیٰ ذہانتوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے میں اگر کوئی فکری منہج سب سے زیادہ مؤثر اور ہمہ گیر کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ شاہ صاحب کی فکر ہی ہے۔ ان کی اجتہادی وسعت، اصولی گہرائی، اور آفاقی نگاہ ہمیں یہ اعتماد دلاتی ہے کہ دینِ اسلام اپنی ابدی معنویت کے ساتھ نہ صرف موجودہ زمانے بلکہ آنے والے ادوار کے سوالات کا بھی جواب دے سکتا ہے۔
تاہم اس کے ساتھ ہی میں اس امر کے اعتراف میں کوئی تردّد محسوس نہیں کرتا کہ دعوتی افق پر آج فکرِ فراہی—اور زیادہ دقیق الفاظ میں کہا جائے تو جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر—اپنے معانی و مضمرات کے ساتھ دنیا کے نقشے پر اپنا وجود منوا رہی ہے۔ اس کی اشاعت اور قبولیت میں روز افزوں اضافہ ہے اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ وہ اپنے دعوتی بیانیے کے جھنڈے زمین پر نصب کر چکی ہے۔ اس اعتبار سے اگر اس فکر کی راہ میں کوئی حقیقی مزاحم یا رکاوٹ بننے والا عنصر ہے، تو وہ محض تجدد دشمنی نہیں، بلکہ شاہ صاحب کی فکر کی اپنی اصالت اور اس کا بے نیازی پر مبنی استغنا ہے۔ گویا شاہ صاحب کی فکر کی قوت اور اس کی ہمہ گیری ہی ایسی ہے کہ وہ کسی دوسرے متوازی تجددی منہج کے لیے سب سے بڑی فکری چیلنج بن سکتی ہے۔
البتہ یہاں ایک وضاحت ناگزیر ہے کہ میری مراد شاہ صاحب کی وہ فکر نہیں ہے جسے آج کل ادارہ رحیمیہ علومِ قرآنیہ کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے نزدیک وہ درحقیقت شاہ صاحب کی فکر کا ایک مسخ شدہ اور غیر متوازن چہرہ ہے، جو اصل ولی اللّٰہی منہج کی روحانی و اجتہادی وسعت کو محدود اور معطل کر دیتا ہے۔ شاہ صاحب کی اصل فکر کو اسی کی اصالت اور جامعیت کے ساتھ سمجھنا اور آگے بڑھانا ہی وقت کی ضرورت ہے۔
چوتھا شذرہ:
عندی، ہر وہ فکری منہج جو انسانی عمل سے اپنا رشتہ کاٹ لے اور محض تجریدی خیالات یا خودساختہ معیارات کے حصار میں محبوس ہو جائے، درحقیقت ایک خطرناک گمراہی ہے۔ ایسا منہج اہلِ فکر کو زندہ حقیقتوں سے کاٹ کر محض آرزوؤں اور تمنّیات کے سراب میں الجھا دیتا ہے۔ یہ سراب بظاہر دلکش اور پرکشش معلوم ہوتا ہے، لیکن اپنی حقیقت میں وہی ہے جسے میں بلا تردّد فکری ابلیسیت سے تعبیر کرتا ہوں کیونکہ وہ انسان کو عمل کے میدان سے نکال کر محض خیالات اور توہمات کی اسیری میں مبتلا کر دیتا ہے۔
عمل، بلاشبہ، خطا اور صواب کے امکانات سے خالی نہیں۔ کسی عمل کی صحت پر نقد یا اس کی خطا پر کلام کرنا ایک فطری اور علمی امر ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ رویہ جس میں صرف انقلاب کے خواب دیکھے جائیں، یا نوحہگری کی ایسی کیفیت پیدا کی جائے گویا ماضی کی پوری تاریخ لاحاصل رہی ہے اور گویا اُمت کے اکابرین نے کچھ سمجھا ہی نہیں، دراصل ناانصافی اور بےبصیرتی ہے۔ یہ طرزِ فکر ایک ایسے شخص کی عکاسی کرتا ہے جو نہ صرف مایوسی کا شکار ہے بلکہ اپنے اس مایوسی زدہ مزاج کو ایک فکری بیانیہ بنا بیٹھا ہے۔
ماضی میں بے شمار فکری و عملی کاوشیں ہوئیں، عظیم ذہانتوں نے اپنے اپنے عہد کے چیلنجز کا مقابلہ کیا، اور امت کے اجتماعی شعور نے کئی نشیب و فراز طے کیے۔ اس سارے عمل کو یکسر جہالت یا غفلت سے تعبیر کرنا دراصل ماضی کی نفی ہی نہیں بلکہ اپنے حال اور مستقبل کی بنیادوں کو بھی کھوکھلا کرنے کے مترادف ہے۔ ایسے رویے کا صدور کسی رجلِ رشید سے نہیں ہو سکتا۔ یہ دراصل ایک غیر رشیدانہ، مایوسانہ اور سطحی فکر کی علامت ہے، جو اپنے اندر اصلاح و تعمیر کا حوصلہ رکھنے کے بجائے محض شکوہ و شکایت میں غرق رہتی ہے۔
پس عندی یہ لازم ہے کہ فکر و عمل کا رشتہ ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ نقد و نظر ضرور ہو، لیکن اس نقد کے ساتھ وہ امید، وسعت اور تعمیری بصیرت بھی شامل ہو جو ہمیں نہ صرف ماضی سے جوڑتی ہے بلکہ حال کو بہتر بنانے اور مستقبل کو سنوارنے کا راستہ بھی فراہم کرتی ہے۔